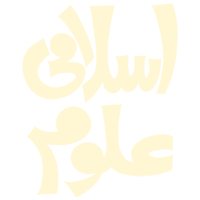مشکوٰة شر یف
نرمی و مہربانی حیاء اور حسن خلق کا بیان
نرمی و مہربانی حیاء اور حسن خلق کا بیان
حذر حا اور ذال کے زبر اور راء کے جز کے ساتھ کے معنی ہیں بچنا پرہیز کرنا، چوکنا رہنا، اور حذر کے زبر اور ذال کے زیر کے ساتھ بیدار و مستعد مرد کو کہتے ہیں۔تانی کے معنی ہیں کسی کام و معاملہ میں جلدی بازی اختیار کرنے کے بجائے توقف و تاخیر کرنا اور اچھی طرح غور و فکر کر لینا، عنوان بالا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے شر زمانہ کی آفات اور ماحول و معاشرہ کے فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو بچائے ان آفات و فتنہ و فساد کا تعلق خواہ دنیاوی نقصانات و مضرات سے ہو یا دینی و اخروی نقصان و تباہی سے اسی طرح چاہیے کہ وہ اپنے کام اور معاملات میں ہمیشہ ہوشیار اور چوکنا رہے، عجلت پسندی اور جلد بازی سے احتراز کرے حلم وقار اختیار کرے اپنے ہر ارادہ و عمل پر اچھی طرح و غور و فکر کیا کرے اور ہر کام کے انجام و مال پر بہتر صورت نظر رکھے۔
ایک حکیمانہ اصول
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔ (بخاری و مسلم)
تشریح
لدغ کے معنی ہیں ڈسنا، سانپ اور بچھو کا کاٹنا، جحر سوراخ اور بل کو کہتے ہیں جو سانپ اور بچھو وغیرہ کا مسکن ہوتا ہے۔
حدیث کا مقصد اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مومن دانا جو حق و انصاف کا علم بردار اور دین کا حامی و محافظ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی عہد شکن اور سرکش سے، جو دین کا دشمن ہے درگزر نہ کرے خدا کی راہ میں اور خدا کی خاطر اس کو اپنے غضب و انتقام کا نشانہ بنانے سے نہ چوکے، بار بار حلم و بردباری اور چشم پوشی کا رویہ اختیار نہ کرے اور اس کے دھوکہ میں نہ آئے واضح رہے کہ کسی دنیاوی معاملہ میں فریب کھا جانا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا مگر کسی دین کے معاملہ میں فریب نہ کھانا چاہیے۔علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مذکورہ ارشاد گرامی میں جس حکیمانہ اصول کی طرف اشارہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عظیم الشان تعلیم ہے جس کی بنیاد دین کی رعایت و حمایت اور دشمنان دین کے شر و فساد کی بیخ کنی ہے۔ مذکورہ بالا ارشاد گرامی کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں عرب کا ایک مشہور شاعر ابوغرہ تھا اور اس کا تعلق کفار کے اس طبقہ سے تھا جو اسلام، ذات رسالت پناہ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت اور سب شتم کے پہاڑ تراشنے پر مامور تھے چنانچہ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ مسلمانوں کی ہجو کیا کرتا تھا اور اپنی قوم کے شریر لوگوں کو مسلمانوں کی ایذاء و اہانت پر اکسایا کرتا تھا جب بدر کے میدان میں حق باطل کے درمیان پہلی معرکہ آرائی ہوئی اور خدا نے اپنے مٹھی بھر بندوں کو دشمنان دین پر فتح عطا فرمائی اور مکہ کے بہت سارے کفار جس میں ان کے زعماء و اساطین بھی تھے قیدی بنا کر مدینہ منورہ لے گئے تو ان میں وہ بد بخت شاعر ابوغرہ بھی تھا اس نے بارگاہ رسالت میں اپنے پچھلے سیاہ ناموں پر اظہار ندامت کیا اور عفو خواہی کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اب میں کبھی بھی ایسے افعال بد کے پاس نہیں پھٹکوں گا۔چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو اس بد بخت پر رحم و کرم کرنے کا موقع مل گیا اور آپ نے اس کے عہد و پیمان کی بنیاد پر اس کو رہا کر دیا لیکن اس کی ازلی شفاعت و بد بختی نے اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور وہ اپنی قوم میں پہنچ کر پہلی روش پر چلنے لگا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو دوبارہ جنگ احد کے موقع پر قیدی کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا اس نے اس مرتبہ بھی وہی عہد و پیمان کا حربہ استعمال کیا اور اظہار ندامت و عفو خواہی کے ساتھ امان چاہنے لگا اور آئندہ اپنی ان حرکتوں سے باز رہنے کا عہد و پیمان کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو جہنم رسید کر دینے کا حکم فرمایا۔چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس وقت جب بعض لوگوں نے اس کی سفارش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے درخواست کی کہ اس کو ایک مرتبہ اور معاف فرما دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔
حلم و بردباری اور توقف و آہستگی کی فضیلت
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے قبیلہ عبدالقیس کے سردار اشج سے فرمایا کہ تمہارے اندر جو دو خوبیاں ہیں ان کو اللہ بہت پسند کرتا ہے (خواہ کسی شخص میں ہوں حلم و بردباری اور دوسرے توقف و آہستگی۔ (مسلم)
تشریح
عبدالقیس ایک قبیلہ کا نام ہے جب اس قبیلہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زیارت و ملاقات کے لیے مدینہ آئے اور مسجد نبوی کے سامنے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھ کر فرط شوق سے اپنے اونٹوں سے کود پڑے بے تابانہ اور دیوانہ وار دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے تئیں محبت و عقیدت اور شوق ملاقات کی بے قراری کا اظہار نہایت جذباتی طور پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو اس بیقرار اور مضطرب حالت میں دیکھا تو سکوت فرمایا ان سے کچھ نہیں کہا لیکن یہ لوگ عظیم المرتبت شخصیت اور اپنے سردار یعنی اشج کی زیر قیادت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور جن کا اصل نام منذر تھا ان کی کیفیت بالکل دوسری تھی وہ پہلے اپنی قیام گاہ پر اترے وہاں انہوں نے اپنے تمام رفقاء کا سامان جمع کیا اور ساری چیزوں کو باندھ کر اطمینان کے ساتھ نہائے دھوئے نہایت نفیس پاکیزہ زیب تن کیے اور پھر انتہائی وقار و تمکنت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کی دعا مانگی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو ان کی یہ وضع اور روش بہت پسند آئی اور ان سے مذکورہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے۔
ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے سامنے ان دونوں خوبیوں کا ہونا بیان فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر جو یہ دو خوبیاں ہیں ان کو میں نے از راہ تکلف اختیار کیا ہے اور میری خود ساختہ ہیں یا اللہ تعالی نے ان کو میری فطرت میں پیدا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں خوبیوں کو تمہارے مزاج و فطرت میں ودیعت رکھا ہے یہ سن کر انہوں نے کہا کہ خدا کا لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے مجھ کو ان دو خوبیوں کے ساتھ استوار کیا جن کو خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے یعنی اگر یہ دونوں خوبیاں میری خود ساختہ اور از راہ تکلف اختیار کی ہوئی ہوتیں تو ان کے زائل ہونے یا ان میں نقصان پیدا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے مگر چونکہ فطری طور پر ہیں اور خدا کی عطا کی ہوئی ہیں اس لیے میں بجا طور پر امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں میرے اندر ہمیشہ رہیں گے اور باقی رہیں گے۔
آہستگی و بردباری کی فضیلت اور جلد بازی کی مذمت
اور حضرت سہل بن ساعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی کام میں آہستگی و بردباری اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ خوبی الہام خداوندی کے ذریعہ کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے اور جلد بازی شیطان کی خصلت ہے اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے نیز بعض محدثین نے اس حدیث کے راوی عبدالمہیمن ابن عباس کی یاد داشت کے بارے میں کلام کیا ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ عبدالمہیمن کا حافظہ زیادہ اچھا نہیں تھا اگرچہ ان کے عدل و ثقہ میں کوئی شبہ نہیں۔
تشریح
اس حدیث کو بیہقی نے بھی شعب الایمان میں بطریق مرفوع نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ التانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔
اور جلد بازی شیطان کی خصلت ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دنیاوی کام میں غور و فکر نہ کرنا، اس کے انجام پر نظر رکھے بغیر اس کو شروع کر دینا اور جلد بازی کی روش اختیار کرنا ایک ایسی خصلت ہے جس کو شیطان وسوسوں اور واہمات کے ذریعہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جس سے اس کا مقصد اس کے کام کو خراب کرنا ہے اور خود اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا ہے بعض حضرات نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے وہ امور مستثنیٰ ہیں جن کی خیر و برکت میں کوئی شبہ نہیں یعنی اچھی چیزوں میں غفلت کرنا شیطان کی خصلت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا، یسارعون فی الخیرات۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جہاں تک عبادات و طاعات کا تعلق ہے تو جاننا چاہیے کہ ایک تو کسی عبادت و طاعت کی طرف سرعت و جلد رویہ کو اختیار کرنا ہے اور دوسرے اس عبادات و طاعت کو کرتے وقت جلد بازی کرنا ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے چنانچہ اول الذکر ایک مطلوب و مستحسن چیز ہے اور ثانی الذکر ایک مذموم خصلت ہے اس بات کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جائے کہ ایک تو نماز کے لیے جلدی کرنا اور ایک نماز میں جلدی کرنا نماز کے لیے جلدی کرنا تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا جلدی جلدی تیاری کرے نماز پڑھنے لگے۔ یہ چیز صرف یہ ہے کہ اس جلد بازی میں شامل نہیں ہے جس کی برائی بیان کی گئی ہے بلکہ یہ ایک مستحسن عمل ہے اور نماز میں جلدی کرنا یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے تو اس نماز سے جلد از جلد فارغ ہو جانے کی خاطر اس کے ارکان و افعال کی ادائیگی میں عجلت کرنے لگے یہ چیز یعنی کسی نیک کام کو جلد بازی سے پورا کرنا مذموم ہے لہذا ملا علی قاری کے مذکورہ الفاظ کا حاصل یہ نکلا کہ فرق شوق سے کسی اچھے کام کی طرف لپکنا اور اس کی انجام دہی کے لیے جلد از جلد تیار ہونا ایک اچھی چیز ہے اور اس اچھے کام کو جلد بازی کے ساتھ کرنا ایک بری چیز ہے۔
تجربہ سب سے بڑی دانائی ہے
اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص کامل بردبار نہیں ہوتا جب تک اس کو لغزش نہ ہوئی ہو اور کوئی شخص کامل حکیم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو تجربہ حاصل نہ ہوا ہو اس روایت کو احمد، اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔
تشریح
حدیث کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ حلم و بردباری اور لحاظ و مروت کا جو ہر شخص میں ہوتا ہے جس نے دھوکا کھایا ہو لغزشوں اور خطاؤں سے دوچار ہوا ہو گناہ و معصیت کا مرتکب ہو چکا ہو اور اپنے معاملات میں خلل نقصان برداشت کر چکا ہو اور ہوشیار ہونے کے بعد ندامت و خجالت کا بار گراں کاندھوں پر اٹھائے پھرا ہو ظاہر ہے کہ ایسا شخص چونکہ اچھی طرح جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی کے دکھ درد اور نفع نقصان کی کیا اہمیت ہوتی ہے کسی کے عیوب چھپانے اور کسی کی خطاؤں کی سے درگزر کرنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ دوسروں کے تئیں حلم و بردبار اور خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اگر کسی سے کوئی خطا ہو جا تی ہے تو اس سے درگزر کرتا ہے۔
حکیم اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو دانا و عقل مند ہے راست باز ہو کیونکہ حکمت کے معنی ہیں ہر چیز کی حقیقت و اصلیت کو جاننا اور تجرمہ کا مطلب ہے کاموں کی واقفیت حاصل کرنا اور کسی کام کو کرنے کا طریقہ جانتا لہذا فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کو اشیاء کی حقیقت و پہچان حاصل ہوئی ہو ہر چیز کے نفع نقصان سے آگاہ ہوا حالات کے اتار چڑھاؤ اور معاملات و افراد کی بھلائی برائی سے وقف ہو اس کو حکمت کی دولت مل گئی اور وہ کامل حکیم ہوا۔ اور اگر حکیم سے طبیب مراد لیا جائے تو بھی مطلب بالکل صاف ہے کہ کوئی شخص محض علم طب پڑھنے سے کامل و معالج نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لیے تجربہ اور معالجہ کی مشق و مزاولت ضروری ہے۔
وہی کام کرو جس کا انجام اچھا نظر آئے
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو کوئی ایسی وصیت فرما دیں جس پر میں اپنے کاموں اور معاملات میں عمل کروں اور جس کی وجہ سے میرا کوئی عمل و کام بگڑ نے نہ پائے۔ حضور نے فرمایا تم جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو تدبر اختیار کرو یعنی انجام پر نظر ڈالو اور اس کے تمام مصلح و مفاسد پر اچھی طرح غور و فکر کر لو اور پھر اگر تمہیں اس کام کے انجام میں دینی خیر و بھلائی نظر آئے تو اس کو کرو اور اگر تمہیں اس کے انجام میں کسی دینی یا دنیاوی گمراہی و اخروی خوف محسوس ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ (شرح السنہ)
توقف و تاخیر نہ کرو
اور حضرت مصعب بن سعد نے اپنے والد سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے راوی حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس حدیث کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نقل کیا ہے اور وہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا توقف و تاخیر ہر عمل میں بہتر ہے مگر آخرت کے عمل میں نہیں۔ (ابوداؤد)
تشریح
مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں توقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو فوراً کر لینا چاہیے کیونکہ نیک کام میں تاخیر کا مطلب بہت سی آفات اور کوتاہیوں کا خطرہ مول لینا ہے علاوہ ازیں دنیاوی امور کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی دنیاوی کام کو کیا جائے تو ابتداء میں عام طور پر اس کے انجام کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ آیا اس کا انجام یقینی طور پر اچھا ہو گا جس کی وجہ سے اس کو فوراً کر لینا ضروری ہو یا اچھا نہیں ہو گا کہ اس کے کرنے میں تاخیر کی جائے لہذا تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے دنیاوی کام میں توقف و تاخیر اختیار کر لو اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لو اس کے خلاف دینی کاموں کا انجام چونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم نہ ہو اس لیے ان میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی علاوہ ازیں قرآن کریم میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ نیکی بھلائی کے کاموں میں سبقت عجلت کرو اور مغفرت و بخشش کی طرف لپکو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔
تشریح
امام غزالی نے اللہ کے ارشاد آیت (الشیطان یعدکم الفقر) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ جونہی اس کے دل میں خدا کے نام پر اپنا مال خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو وہ اس نیک کام میں قطعاً تاخیر نہ کرے کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے کہ اگر اپنا مال خرچ کر دے گا تو کنگال ہو جائے گا اسی طرح وہ اس کو فقر افلاس سے ڈراتا ہے اور صدقہ خیرات کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لہذا توقف تاخیر کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شیطان کا داؤ چل جائے اور اس نیکی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دن بیت الخلاء میں تھے کہ انہوں نے وہیں سے اپنے شاگرد کو آواز دی کہا کہ میرے بدن کی قمیص اتار کر فلاں شخص کو دے دو شاگرد نے یہ سن کر کہا یہ بات آپ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی کہہ سکتے تھے اس قدر بے صبری کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں یہ قمیص فلاں ضرورت مند کو دیدوں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ فوراً یہ نیک کام کر دوں کیونکہ میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا نہ معلوم اس کا ارادہ کب بدل جائے اور میں اس نیکی سے محروم رہ جاؤں۔
نبوت سے تعلق رکھنے والی صفات کا ذکر
اور حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا نیک راہ روش کسی کام میں آہستگی اور غور و فکر کے لیے تاخیر کرنا، اور میانہ روی وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کے چوبیس اجزاء سے ایک جز ہے۔ (ترمذی)
تشریح
میانہ روی کے معنی ہیں کہ ہر کام اور ہر حالت میں درمیانی راہ اختیار کرنا اور افراط و تفریط سے اجتناب کرنا جیسے خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرنا اور نہ بخل کرنا بلکہ درمیانی طریقہ یعنی جود و سخاوت اخیتار کرنا۔ یا ہمت و حوصلہ کے اظہار کے موقع پر نہ تو تہور دکھانا اور نہ بزدل بن جانا بلکہ درمیانی راہ شجاعت کو اختیار کرنا یا اعتقادی اور نظریاتی معاملات میں بھی میانہ روی اختیار کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اسی عقیدہ پر اعتماد کیا جائے اور وہی نظریہ اپنایا جائے جو دین و دیانت اور عقل دانش کے اعتبار سے معتدل سمجھا جائے مثلاً ایک عقیدہ جبر کا ہے اور ایک قدر کا ہے یہ دونوں عقیدے افراط کے حامل ہیں ان دونوں کے برخلاف درمیانی عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے اسی طرح میانہ روی اختیار کرنے کے حکم کا تعلق معیشت سے ہے اور اس کی درمیانی عقیدہ وہ ضروریات زندگی پر نہ تو اتنا خرچ کیا جائے جو اسراف و عیش کی حد تک ہو اور نہ اس قدر کم خرچ کیا جائے جو تنگی تکلیف میں مبتلا کر دے بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پیدا کیا جائے جیسا کہ خود ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا آدھا سرمایہ ہے۔غرض کہ انسانی زندگی کے ہر گوشہ اور ہر فعل عمل میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے اور یہی چیز یعنی ہر ایک امر میں اعتدال اختیار کرنا وہ کمال ہے جو انسان کو اس کی مراد اور اس کے مقاصد تک پہنچاتا ہے کیونکہ بہت دوڑ کر چلنے والا گر جاتا ہے اور سست رفتاری سے چلنے والا بچھڑ جاتا ہے صرف اعتدال کی چال چل کر ہی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے متعدد مواقع پر راہ اعتدال کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف سے اجتناب کرو۔ بعض عارفین نے کہا ہے کہ علم و عمل میں بھی میانہ روی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے مختلف عملی آفات سے بچا جا سکتا ہے چنانچہ حصول علم میں اتنی مشغولیت بہتر ہے جو عمل سے باز نہ رکھے اور عمل میں اسی قدر انہماک روا ہے جو حصول علم سے باز نہ رکھے۔ نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ یا تو یہ سب چیزیں مل کر ایک جزء کا درجہ رکھتی ہیں یا ان میں سے ہر ایک چیز ایک جزء ہے اور اس کا جزء کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوبیاں اور صفات ان خوبیوں اور صفات میں سے ایک ہیں جن سے انبیاء کرام متصف مزین ہوتے ہیں رہی یہ بات کی اجزاء نبوت کے عدد کے تعین سے کیا مراد ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی مراد صرف شارع ہی بیان فرما سکتے ہیں جس کو بیان نہیں فرمایا گیا یوں بیان کرنے کو مختلف باتیں کہی جا سکتی ہیں مگر اس کی حقیقت تک چونکہ نور نبوت کے علاوہ کوئی بھی انسانی فہم و ادراک نہیں پہنچ سکتا اس لیے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنا چاہیے۔
ٍ
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا نیک سیرت نیک راہ روش اور میانہ روی وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں۔ (ابوداؤد)
تشریح
ہدی صالح اور سمت صالح کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہدی کا تعلق انسان کے باطنی احوال سے ہے اسی لیے اس کا ترجمہ نیک سیرت کیا گیا ہے جس کو نیک خونی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور سمت کا تعلق انسان کے ظاہری احوال کردار سے ہے اس لیے اس کا ترجمہ نیک راہ روش کیا گیا ہے اس کو نیک چلنی بھی کہا جاتا ہے راہ سلوک و طریقت میں ان دونوں کا وہی درجہ ہے جو شریعت میں ایمان و اسلام کا ہے اس اعتبار سے نیک خوئی اور نیک چلنی یہ دونوں خوبیاں ایک ساتھ جس مومن میں ہوں تو نور علی نور اور اس کے مرتبہ حقیقت کے کامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس حدیث میں ان خوبیوں کو نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزء کہا گیا ہے جب کہ پچھلی حدیث میں چوبیس کا عدد منقول ہوا ہے لہذا دونوں روایتوں میں یہ تفاوت و فرق یا تو کسی راوی کے وہم و خطا میں مبتلا ہو جانے کی بنا پر ہے یا اس میں بھی کوئی بھید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے کسی موقع پر چوبیس کا عدد ذکر فرمایا ہے اور کسی موقع پر پچیس کا۔
یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہی فرمایا کہ یہ خوبیاں نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں اور پھر آپ نے از راہ عنایت ان خوبیوں کا ایک درجہ اور بڑھا دیا اور یہ فرمایا کہ یہ خوبیاں نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں یا یہ کہ پچھلی حدیث میں جن تین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مل کر چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء کا درجہ پاتی ہیں اور اس حدیث میں جن تین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مل کر پچیس اجزاء میں سے ایک جزء کا درجہ پاتی ہیں اس صورت میں یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ راوی کے وہم و خطا میں مبتلا ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ اس سے ایک روایت میں چوبیس کا عدد نقل کیا ہے اور ایک روایت میں پچیس کا۔
کسی کا راز امانت کی طرح ہے
اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کوئی ایسی بات کہے جس کا وہ اخفاء چاہتا ہوں اور پھر وہ چلا جائے تو اس کی وہ بات امانت ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)
تشریح
مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ بات سننے والوں کے لیے ایک امانت کا حکم رکھتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس امانت میں خیانت نہ کریں یعنی اس کو ظاہر نہ کریں۔
مشورہ چاہنے والے کو وہی مشورہ دو جس میں اس کی بھلائی ہو
اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک صحابی ابوالہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خادم ہے انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس کہیں سے غلام آئیں تو تم آ جانا میں تمہیں ایک غلام دے دوں گا چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس دو غلام آئے تو ابوالہیثم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا کہ یہ دو غلام ہیں ان دونوں میں سے کسی کو اپنے لیے پسند کر لو۔ ابوالہیثم نے عرض کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم آپ ہی میرے لیے کوئی غلام پسند فرما دیں حضور نے فرمایا جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے یعنی مشیر کو چاہیے کہ مشورہ چاہنے والے کی بھلائی کو بہر صورت ملحوظ رکھنا چاہیے اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو گویا حضور نے اس ارشاد کے ذریعہ ابوالہیثم پر واضح کر دیا جب تم نے حق کا انتخاب میرے سپرد کر دیا ہے اور مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میں تمہیں وہی غلام دوں گا جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اس غلام کو لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بھلائی اختیار کرنے کی میری وصیت پر ہمیشہ عمل کرنا۔ (ترمذی)
تشریح
ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت ابوالہیثم اس غلام کو گھر لے کر آئے اور اہلیہ سے فرمایا کہ سرکار نے مجھ کو یہ غلام دیا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی تو ان کی بیوی نے کہا اس وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حق شاید پوری طرح ادا نہ ہو سکے اس کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔
وہ تین باتیں جو کسی کا راز بھی ہوں ان کو ظاہر کر دو
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجلسیں امانت کے ساتھ وابستہ ہیں البتہ تین مجلسیں یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہیں کوئی بات کی جائے تو دوسروں تک ان کو پہنچا دینا ضروری ہے (خواہ کہنے والا ان باتوں کو کتنا ہی اہم راز کیوں نہ سمجھے اور وہ تینوں یہ ہیں، (١) جس خون کو ناحق بہانا حرام ہے اس کو بہانے (یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے کے مشورہ ارادہ کی بات) (٢) حرام کاری یعنی زنا کرنے کے مشورہ و ارادہ کی بات (٣) کسی کا مال ناحق چھیننے کے مشورہ و ارادہ کی بات۔ (ابوداؤد) اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت باب المباشرۃ کی پہلی فصل میں ذکر کی جا چکی ہے۔
تشریح
مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے یہ بات سنے کہ میں فلاں آدمی کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کروں گا یا فلاں شخص کا مال زور زبردستی ہتھیاؤں گا تو اس طرح کی اس بات سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو ایسا راز نہ سمجھے جس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اس کو فوراً ظاہر کر دے یعنی اس بات سے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دے تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں اسی طرح مجلس کی باتوں کا افشاء کرنا بھی جائز ہے جن میں دین و ملت اور قوم کا نقصان ہو یہ مطلب حضرت شیخ عبدالحق نے لکھا ہے۔
اور ملا علی قاری نے اس حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا ہے اس کی روشنی میں مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں لوگوں کو کوئی برا کام کرتے دیکھے تو وہ ان کی اس بدعملی کا چرچا کرتا نہ پھرے پھر البتہ تین مجلسیں ایسی ہیں کہ ان میں کی جانے والی برائیوں کا چرچا کیا جا سکتا ہے جن میں سے ایک مجلس وہ ہے جس میں کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہو، دوسری مجلس وہ ہے جس میں کسی عورت کی عصمت لوٹی جا رہی ہو اور تیسری مجلس وہ ہے جس میں کسی شخص کا مال ناحق ہتھیایا جا رہا ہو۔
عقل کی تعریف و اہمیت
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ کھڑی ہو جا وہ کھڑی ہو گئی پھر اس سے فرمایا کہ پشت پھیر اس نے پشت پھیر لی پھر اس سے فرمایا کہ میری طرف منہ کر اس نے خدا کی طرف منہ کر لیا پھر اس سے فرمایا کہ بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی اور پھر فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو تجھ سے بہتر ہو فضل و کمال میں تجھ سے بڑھی ہوئی ہو اور خوبیوں میں تجھ سے اچھی ہو میں تیرے ہی سبب بندوں سے عبادت لیتا ہوں یعنی تیری رہنمائی کے ذریعے بندے میری عبادت کرتے ہیں یا یہ کہ تیرے ہی سبب بندوں سے نعمتیں واپس لیتا ہوں بایں طور کہ جو بندے تیرے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو وہ میرے غضب میں مبتلا ہو کر میرے انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں تیرے ہی سبب سے بندوں کو ثواب درجات دیتا ہوں میں تیرے ہی سبب سے پہچانا جاتا ہوں میں تیرے ہی سبب سے غضبناک ہوتا ہوں میں تیرے ہی سبب سے ثواب دیتا ہوں اور تیرے ہی سبب سے عذاب دیتا ہوں۔ بعض علماء نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔
تشریح
حدیث کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے عقل کو جسم کے ساتھ پیدا کیا تھا جیسا کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد موت کو دنبہ کی صورت میں لایا جائے گا اور پھر اس کو جنت دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔
قیامت کے دن عقل کے مطابق جزاء ملے گی
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہو، روزہ رکھنے والوں میں سے ہو زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو، حج و عمرہ کرنے والوں میں سے ہو یہاں تک کہ آپ نے اسی طرح نیکی بھلائی سے متعلق ساری بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لیکن وہ قیامت کے دن اپنی عقل کے مطابق جزاء پائے گا۔
تشریح
ان حدیثوں میں عقل سے مراد وہ اعلیٰ جوہر ہے جس کے ذریعہ انسان اشیاء و اسباب کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور برائیوں کو معلوم کرتا ہے نیکی اور بدی کے درمیان فرق و امتیاز کرتا ہے نفس کی آفات اور گمراہیوں سے اجتناب کرتا ہے نیک راہ روش اختیار کرتا ہے اللہ کا قرب و اتصال حاصل کرتا ہے، بعض عارفین کے کلام میں جس عقل عماد کا ذکر آتا ہے اس سے یہی عقل مراد ہے یہ اعلیٰ جوہر جس شخص میں جس نوعیت کا ہوتا ہے اس کے اندر مذکورہ بالا اوصاف بھی اس کے تناسب سے ہوتے ہیں اسی لیے فرمایا گیا کہ جس شخص میں جتنی عقل ہو گی وہ اس کو قیامت کے دن اسی کے مطابق جزاء دی جائے گی کیونکہ خدا کی طرف سے جزاء و انعام کا مدار محض عبادات و طاعت یا عبادات و طاعات کی مقدار پر نہیں ہو گا بلکہ عبادت کے حسن و کمال پر ہو گا اور ظاہر ہے کہ عبادات و طاعات میں حسن کمال کیفیت اسی عقل سے متعلق ہے۔ اسی موقع پر علماء اس بارے میں بحث و اختلاف کرتے ہیں کہ آیا علم افضل ہے کہ یا عقل، چنانچہ بعض حضرات نے علم کو افضل قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے عقل کو لیکن اگر یہ کہا جائے کہ علم کا معنوی اطلاق بھی قوت تمیز معرفت پر ہوتا ہے جو عقل کی روشنی میں پائی جاتی ہے تو اس صورت میں بحث اختلاف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس اعتبار سے یہ بات البتہ کہی جا سکتی ہے کہ علم عقل کو عمل و عبادت پر فضیلت حاصل ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ صاحب عقل عالم کی ایک رکعت نماز دوسرے لوگوں کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل قرار پائے گی۔
تدبر کی فضیلت
اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ابوذر جان لو عمل تدبیر کے برابر نہیں، ورع یعنی پرہیزگاری اجتناب و احتیاط کے برابر نہیں اور حسب و فضیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے۔
تشریح
تدبیر کے معنی ہیں ہر کام کے انجام پر نظر رکھ کر اس کے لیے سامان پیدا کرنا لہذا عقل تدبیر کے مانند نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عقل عقل تدبیر کے برابر نہیں ہو سکتی گویا مذکورہ جملہ میں عقل سے مراد مطلق علم و ادراک ہے تدبیر سے مراد عقل تدبیر ہے جس کا مطلب یہ ہے جو کام بھی کیا جائے پہلے اس انجام پر نظر رکھی جائے اور اس میں جو بھلائیاں و برائیاں ہوں ان کو پہچانا جائے۔
ورع کے معنی پرہیزگاری کے ہیں جس کو تقوی بھی کہا جاتا ہے اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک ورع اور تقوی کے درمیان بھی فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ ورع کا درجہ تقوی کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے بایں طور پر کہ تقوی کا مطلب ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور تورع کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا جو مکروہ یا مشتبہ ہوں لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ تقوی اور تورع دونوں ایک ہی معنی ہیں اور عام طور پر سب لوگ ان دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اب رہی یہ بات کہ حدیث میں جو دو لفظ روع اور کف نقل کیے گئے ہیں ان میں سے ورع کا ترجمہ پرہیز گاری اور کف کا ترجمہ اجتناب و احتیاط کیا گیا ہے۔تو کیا ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیونکہ ورع کے معنی ہیں باز رہنا اور کف کے معنی ہیں باز رہنے کے ہیں اس صورت میں حدیث کے اس جملہ لاورع پر اشکال ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ یوں ہوں گا باز رہنا، یا رہنے کے برابر نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح اس جملہ کے کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے چنانچہ طیبی نے اس حدیث کی شرح میں اس اشکال کو ظاہر کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کف کے معنی مسلمانوں کو ایذاء پہنچانے یا زبان کو لایعنی باتوں میں مشغول کرنے سے پرہیز کرنا ہے اور چونکہ دینی طور پر بھی اور سماجی و معاشرتی طور پر بھی ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک مفاسد اور اس کی برائیاں بہت ہیں اس لیے ان کے مفاسد کو از راہ مبالغہ بیان کرنے کے لیے گویا یہ فرمایا گیا کہ ورع یعنی حرام چیزوں سے باز رہنا اگرچہ ایک اعلیٰ وصف ہے علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ورع تقوی کے لغوی معنی اگرچہ باز رہنا اور پرہیز کرنا ہیں لیکن شرعی طور پر ان کے مفہوم میں امتثال اور اجتناب دونوں ایک ساتھ داخل ہیں اور اگر ان کا مفہوم صرف اجتناب ہی ہو تو احکام کی فرماں برداری ترک کرنے سے پرہیز کرنا بھی ان کے مفہوم میں داخل ہوتا لہذا بات وہی ورع اور تقوی کے مفہوم میں امتثال اور اجتناب دونوں داخل ہیں اور اس صورت میں بھی یہی نکلے گا کہ ورع اور تقوی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو احکام دیئے گئے ہیں ان پر چلا جائے اور ان احکام پر خواہ امتثال کے طور پر ہو یا اجتناب کے طور پر۔ اس طرح جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ورع کا تعلق دو چیزوں سے ہے یعنی جن امور کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کرنا اور جن امور سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہنا اور کف کا تعلق صرف ایک چیز یعنی ممنوعات سے باز رہنے سے ہے تو مذکورہ اشکال رفع ہو گیا اس کے بعد یہ مسئلہ جان لینا چاہے کہ جس سے حدیث کے مذکورہ جملہ کا مفہوم اور زیادہ صاف ہو جائے گا کہ جانب اجتناب کی رعایت جانب امتثال کی رعایت کی بہ نسبت زیادہ مقدم اور زیادہ ضروری ہے یعنی شریعت نے جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ان سے باز رہنا زیادہ ضروری ہے بہ نسبت اس کے کہ جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کیا جائے اسی بناء پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جانب امتثال میں فرض و واجبات اور سنن مؤکدہ پر اکتفا کرے اور نوافل کو ترک کر دے لیکن جانب اجتناب میں خوب اہتمام کرے یعنی تمام حرام مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے تو وہ شخص منزل مقصود پا لے گا یعنی معرفت و حقیقت اور قرب خداوندی کا درجہ حاصل کرے گا اس کے برخلاف اگر کوئی شخص جانب امتثال میں خوب اہتمام کرے لیکن یعنی فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ پر بھی عمل کرے اور نوافل و مستحبات کو بھی ادا کرے لیکن جانب اجتناب کی رعایت نہ کرے یعنی ممنوعات کا ارتکاب کرے تو وہ شخص منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو اور وہ تو پرہیز تو پوری کرے لیکن دوا نہ کھائے تو وہ اچھا ہو جائے گا خواہ کتنی ہی دیر میں اچھا ہو اس کے برخلاف اگر وہ دوائیں کھاتا رہے لیکن پرہیز بالکل نہ کرے تو وہ ہرگز شفاء نہیں پائے گا بلکہ روز بروز بیمار ہوتا چلا جائے گا۔
حسب و فضیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے۔ حسب اصل میں کہتے ہیں کہ اپنے اور اپنے باپ دادا کے فضائل کو گنوانا اور اپنے خاندانی فخریہ کارناموں کو بیان کرنا، اس جملہ میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی ذاتی فضیلت و بزرگی اور انسانیت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اس میں خوش خلقی ہو اگر کوئی شخص خوش خلقی کی صفت سے محروم ہے تو وہ لاکھ اپنے مناقب گنوائے اور لاکھ اپنے فخریہ کارناموں کو بیان کرے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی واضح رہے کہ اگر خوش خلقی میں خلق سے مراد تمام باطنی اوصاف ہوں تو ظاہر ہے کہ حسن اخلاق کو سب سے بہتر اور اصل فضیلت کہا جائے گا اور اگر خلق سے مراد نرم خوئی و مہربانی اور مروت کے اوصاف ہوں جیسا کہ عام طور پر خوش خلقی انہیں اوصاف سے متصف ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ فرمانا کہ حسب و فضیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے خوش خلقی کی فضیلت کو از راہ مبالغہ بیان کرنے کے لیے ہو گا۔
اہل تصوف کے نزدیک خوش خلقی کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی جاتی ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا لوگوں کو اپنی عطا و بخشش سے بہرہ مند کرنا اور خدا کی مخلوق کو ایذاء پہنچانے سے باز رہنا یہ وہ اوصاف ہیں جن پر حسن خلق کا اطلاق ہوتا ہے یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے ایک بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ عداوت ترک کر کے اور راحت و تنگی دونوں حالت میں خوش رہنا چاہیے۔ حضرت سہل تستری کے قول کے مطابق حسن خلق کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے جو زیادتی و سختی پیش آئے اس کو برداشت کرے اور کسی سے انتقام نہ لے ظالم کے حق میں بھی شفیق و مہربان رہے اور اس کی مغفرت کا خواہاں رہے۔
خرچ میں میانہ روی زندگی کا آدھا سرمایہ ہے
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے انسانوں سے دوستی نصف عقل ہے اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا آدھا علم ہے ان چار روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔
تشریح
حدیث کے پہلے جزء کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرنا اور نہ تنگی کرنا بلکہ میانہ راوی اختیار کرنا زندگی کا آدھا سرمایہ ہے بایں طور کہ انسان کی معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایک تو آمدنی دوسری خرچ اور ان دونوں کے درمیان توازن خوشحالی کی علامت ہے اور معیشت کے مستحکم ہونے کا ذریعہ بھی ہے لہذا جس طرح آمدنی کے توازن کا بگڑنا، خوش حالی کے منافی اور معیشت کے عدم استحکام کا سبب ہے اسی طرح اگر اخراجات کا توازن بگڑ جائے تو نہ صرف خوش حالی مفقود ہو گی بلکہ معیشت کا سارا ڈھانچہ درہم برہم ہو جائے گا لہذا مصارف میں اعتدال کرنا میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا نصف حصہ ہوا۔
حدیث کے دوسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ محبت ظاہر کرنا اور ان کی محبت کو اپنے معاملات و احوال میں خیر و برکت کا سرچشمہ جاننا اس عقل کا نصف حصہ ہے جو حسن معاشرت کی ضامن ہے گویا پوری عقل مندی یہ ہے کہ انسان کوئی کسب و پیشہ اور سعی و محنت کر کے جائز روزی حاصل کرے اور اس کے ساتھ آپس میں محبت و مروت کے جذبات بھی رکھے۔
حدیث کے تیسرے جز کا مطلب یہ ہے کہ کسی علمی مسئلہ میں خوب سوچ سمجھ کر اور اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے کیونکہ جو شخص سوال کرنے میں دانا اور سمجھ دار ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہو اور بہت کارآمد ہو اور چوں کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کا متمنی ہوتا ہے اواس کے ساتھ ہی وہ پوچھی جانے والی چیزوں کے درمیان تمیر کرنا جانتا ہے کہ کیا پوچھنا چاہیے اور کس سے پوچھنا چاہیے اس لیے جب وہ اپنے سوال کا جواب پا لیتا ہے تو حل طلب مسئلہ میں اس کا علم پورا ہو جاتا ہے اس اعتبار سے گویا علم کی دو قسمیں ہوئیں ایک تو سوال اور دوسرے جواب۔
رہی یہ بات کہ اچھی طرح سوال کرنے کا مطلب تو جاننا چاہیے کہ اچھے سوال کا اطلاق اس سوال پر ہوتا ہے کہ جس کے تمام پہلوؤں کی تحقیق کر لی گئی ہو۔ اس میں جتنے احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کی واقفیت ہو تاکہ شافی کافی جواب پائے اور جواب میں کوئی پہلو تشنہ نہ رہنے پائے اس طرح کا سوال بذات خود علم کی ایک شق ہو گا اور اس پر یہ اشکال وارد نہ ہو گا کہ جب سوال کرنا جہل اور تردد پر دلالت کرتا ہے تو سوال کرنے کو نصف علم کسی طرح کہا گیا ہے تاہم مذکورہ اشکال کے پیش نظر ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص خوب سوچ سمجھ کر اور صحیح اندازہ میں سوال کرتا ہے کہ اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو علمی ذوق کا حامل ہے اور علم میں اپنا کچھ حصہ ضرور رکھتا ہے اور اس بات کا خواہش مند ہے کہ اپنے ناقص علم کو پورا کرے لہذا اس کے سوال کو نصف علم کہنا موزوں ہو گا اس کے برخلاف جو شخص بغیر سوچے سمجھے اس اور خراب انداز میں سوال کرتا ہے وہ اپنے اس سوال کے ذریعہ اپنے نقصان عقل و کمال اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ سوال کی نوعیت اور سوال کرنے کا انداز سوال کرنے والے کی شخصیت و حالت پر بذات خود دلالت کرتا ہے اور اس کے سوال کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ شخص بالکل ہی جاہل ہے یا علم سے کچھ سروکار رکھتا ہے جس شخص میں علم و عقل کی روشنی ہو گی یہ سوال بھی عالمانہ اور عاقلانہ ہو گا۔ اور جو شخص نرا جاہل ہو گا اس کی اور باتوں کی طرح اس کا سوال بھی جاہلانہ اور عامیانہ ہو گا جیسا کہ کسی نے کہا کہ جب جاہل بات کرتا ہے تو گدھے کی طرح معلوم ہوتا ہے اور جب چپ رہتا ہے تو دیوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔